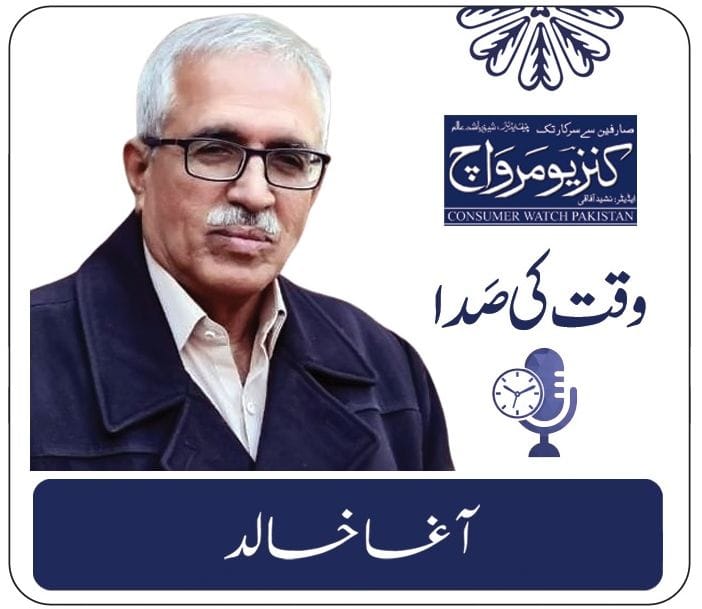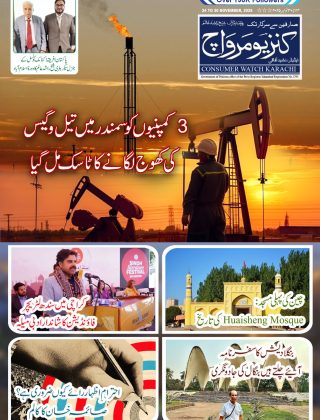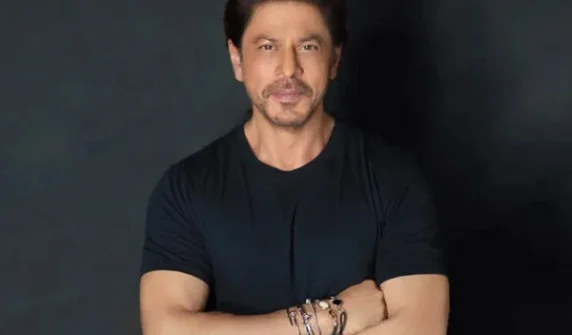لاکھوں دیگر لوگوں کی مانند، یہ عام سا نوجوان بھی اپنے دل میں حسیں خوابوں کا ہار سجائے، اندرون سندھ کے پس ماندہ ضلع دادو سے کراچی پہنچا۔ اس مادی دور میں نہ اسے دولت کی ہوس تھی، نہ جاہ و جلال کی تمنا۔ وہ بس ایک فقیر منش مزاج کے ساتھ انسانیت کی معراج، فلسفہ کی ماہیت، اسباب و علل کی کھوج میں کھو گیا، تقدیر نے اسے سندھ کے سینیر وزیر شرجیل میمن کا پی آر او بنا دیا، مگر سچ یہ ہے کہ یہ اس کی منزل نہیں۔ اس کے کھوجی مزاج کی معراج کہیں اور لکھی گئی ہے۔ نوکری کے فراغت کے لمحوں میں وہ کبھی قدرت کے کمالات پر غور و بحث میں مصروف نظر آتا، کبھی اس کی عطائوں پر شکر گزار، کبھی گورکھ دھندوں پر شکوہ کرتا، اور ٹالسٹائی جیسے دانش وروں کے علوم میں جھانکتا، جبکہ افلاس میں لتھڑا معاشرہ کے لیے خیر کے راستے ڈھونڈتا نظر آتا ہے ، چالیس کی دہائی کے اوائل میں، حسین منصور کی دو تصانیف بازار میں دسترس پا چکی ہیں،
۱۔ آزادی کا ضدی عاشق (سندھی ایڈیشن)
۲۔ کاری-دی بلیک ل، جبکہ اس کی مزید تین کتابیں زیر طباعت ہیں، میں منٹو اور دوستوئیفسکی(نثر)، دل کہ جیسے ریت مٹھی میں (شاعری)، اور شعور ہستی (وجودیت کے فلسفے کا تجزیہ)، جو فلسفہ کے طالب علموں کے لیے سبق آموز ہوں گی اپنے ناول کاری دی بلیک میں حسین منصور نے جو منظر پیش کئے ہیں، وہ حیرت انگیز ہیں، جو کہ قارئین کے لیے پیش خدمت ہیں، “علی نواز کی مدد سے شیرْو نے بچی کو آہستگی سے جیسے ہی گڑھے میں اتارا تب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی قمیص کے نیچے نیفے میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس نے ٹٹولہ ایک دیکھا تو وہ ایک گڑیا تھی، شیرو پر جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ شیرو، جس نے بے شمار عورتوں اور لڑکیوں کو گڑھے کھود کر دفن کیا تھا، کی بے اولادی کی روح تک لرز اٹھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، “کیا مجھے اب بھی ماننا چاہئے کہ تْو واقعی موجود ہے؟” اس طرح ناول میں عاشی کی کہانی بھی بہت بھیانک ہے، آپ کو ایک بار یہ ناول ضرور پڑھنا چاہئے، منصور کے دوست اور ممتاز دانشور اور پبلشر سجاد سومرو لکھتے ہیں کہ “حسین منصور ایک خاموش چیخ، ایک اجنبی شناخت ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حسین منصور کون ہے، تو میں شاید خاموش ہو جاؤں، کیونکہ اسے سمجھنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ اْسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی سناٹا جو چیختا نہیں، مگر دل کے اندر شور مچاتا ہے۔” منصور کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی کی اْس پرت میں جھانکیں جہاں احساسات کا شور ہے مگر آواز نہیں، جہاں سوچ کی گہرائی ہے مگر سمت نہیں، اور جہاں لفظوں کا سمندر ہے مگر کوئی کنارے دستیاب نہیں، اس کا کرب ذاتی دکھ نہیں، بلکہ ایک پورے دور کی اذیت ہے وہ ان سوالوں کا نمائندہ ہے جنہیں آج کا نوجوان پوچھنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی جواب موجود نہیں۔ جب وہ کہتا ہے، “میں دوستوئیفسکی نہیں
ہوں، مگر میں ہوں”, تو یہ محض انکار نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ شناخت کا اعلان ہے۔ دوستوئیفسکی انسان کے اندر کے اندھیرے کو بے خوف دیکھتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ اپنے کرداروں کے ذریعے روشنی کا راستہ نکال دیتا ہے، جبکہ منصور انہی اندھیروں میں گم رہتا ہے اس کے نزدیک دوستوئیفسکی ایک آئینہ ہے جو اسے خود سے ملاتا ہے، مگر ملاقات کے بعد بھی اس کی شناخت دھندلی رہتی ہے۔ اس کا المیہ یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے الگ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے ایک پہیلی ہے۔ منصور کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ وہ بظاہر آزاد ہے، مگر اندر سے قید میں ہے۔ وہ زنجیریں جن کی بات کرتا ہے، عام لوگ دیکھ نہیں سکتے، مگر اْن کی چبھن ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں شریک ہونا اکثر دشوار ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ اکثر احساسات کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جب وہ بولتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ اْس کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہوں۔ یہ کیفیت صرف ادبی یا تخلیقی نہیں، بلکہ ایک گہری وجودی الجھن ہے: زندہ ہونا، مگر زندگی کا کوئی مطلب نہ ہونا منصور کی اردو کی پہلی کتاب میں منٹو اور دوستوئیفسکی ایک علامتی انتخاب نہیں، بلکہ اس کے اندر کی تقسیم کی سچّی تصویر ہے۔ منٹو معاشرے کے بدنما چہرے کو بے نقاب کرتا ہے، دوستوئیفسکی انسان کے اندر کی وحشت کو، اور منصور ان دونوں دھاروں کے درمیان کھڑا وہ مسافر ہے جو کسی کا نہیں بنتا، اس کی تحریروں میں منٹو کا طنز موجود ہے، مگر وہ باہر کی دنیا کے لیے نہیں، اندر کی دنیا کے لیے ہے دوستوئیفسکی کا کرب بھی قاری کے لیے نہیں، بلکہ خود منصور کے لیے ہے، کتاب کے عنوانات، منٹو کا آخری افسانہ، منٹو کا کفن، منٹو کی واپسی، سب منصور کی اپنی واپسی کے استعارے ہیں، میں نے کئی بار حسین کو خاموش گھنٹوں بیٹھا دیکھا، سب کے درمیان مگر سب سے الگ۔ اس کی آنکھوں میں مستقل تھکن تھی، جیسے نیند نہ آنے کی نہیں، جینے کی تھکن ہو۔ اس کی بظاہر معمولی باتوں میں ایک خالی پن کی گہرائی جھلکتی۔ وہ اکثر کہتا، “کاش میں بھی کوئی واضح شخص ہوتا، جیسے سب ہوتے ہیں، خوش یا دکھی، جیتنے والے یا ہارنے والے، مگر میں بس… ہوں” منصور دو وجودوں کی جنگ میں مبتلا ہے، ایک جو محسوس کرتا ہے، اور ایک جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، میں گواہ ہوں کہ وہ دونوں وجود روز لڑتے، تھکتے، اور اسے تھوڑا سا اور توڑ دیتے ہیں، اس دور میں جہاں ہر کوئی آواز بننے کی دوڑ میں ہے، حسین منصور ایک سناٹا ہے، مگر وہ سناٹا جس کی گونج بہت دور تک جاتی ہے، وہ کوئی حل پیش نہیں کرتا، کوئی امید نہیں بیچتا، مگر اس کی سچائی، خواہ وہ اذیت ناک ہو، وہی حقیقت ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ حسین منصور کو پڑھنا آسان نہیں، سمجھنا دشوار ہے، مگر ایک بار اگر سمجھ لیا، تو شاید آپ خود کو بھی تھوڑا سا سمجھنے لگیں، وہ آئینہ ہے جو بگاڑ چھپاتا نہیں، دکھاتا ہے، وہ زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، مگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، منصور شاید کبھی دوستوئیفسکی نہ بنے، مگر اس نے اپنا لہجہ ڈھونڈ لیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور میں، اْس کا دوست، خوش ہوں کہ میں اْس لمحے کا گواہ ہوں جب ایک گمنام لکھاری نے خاموشی میں چیخنے کا فن سیکھا۔
حسین منصور ابھرتا ہوا دانشور (آغاخالد)